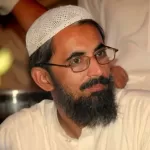سوال
١۔ بعض لوگ خود کش حملے کے جواز کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے ایک راہب کو جب ایمان قبول کرنے کی پاداش میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور اللہ کی مدد سے یہ کوشش بار بار ناکام ہوئی تو اس نے خود اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تجویز کیا کہ لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے اور پھر سب کے سامنے ‘باسم رب هذا الغلام’ کہہ کر اس پر تیر چلایا جائے تو اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس دلیل کی کیا حیثیت ہے؟
٢۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ برطانیہ اور امریکہ کے شہری چونکہ اپنی حکومتوں کو ٹیکس دیتے ہیں، اس لیے اگر ان ممالک کی حکومتیں مسلمانوں پر ظلم کرتی یا ظلم کرنے والوں کے ساتھ تعاون کرتی ہیں تو ان کے شہری بھی اس میں شریک ہیں۔ چنانچہ اگر اسرائیل کے ظلم وستم کا شکار ہونے والا کوئی فلسطینی امریکہ یا برطانیہ میں جا کر ان کے عام شہریوں پر حملہ کرے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟
٣۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے علاوہ انسانوں کے بنائے ہوئے جمہوری قوانین کو قبول کرنا کفر ہے، اس لیے اگر غیر مسلم ممالک میں رہنے والے مسلمانوں نے ان ممالک کے قوانین کی پابندی کا معاہدہ کر رکھا ہو، تب بھی اس کی پابندی ان پر لازم نہیں ہے اور انھیں چاہیے کہ وہ اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کریں۔ یہ خیال دین کی روشنی میں کس حد تک صحیح ہے؟
جواب
١۔ خود کشی کے بارے میں یہ بات بطور اصول سمجھنی چاہیے کہ شریعت میں اس کی ممانعت اصلاً اس صورت کے لیے آئی ہے جب انسان زندگی کی تکالیف او رمصائب سے گھبرا کر خدا کی تقدیر پر صبر ورضا کا رویہ اپنانے کے بجائے اپنی زندگی کے خاتمے کا فیصلہ کر لے۔ یہ رویہ چونکہ خدا اور قضا وقدر کے فیصلوں پر ایمان کے منافی ہے، اس لیے اس کا شمار کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے۔ اگر یہ صورت نہ ہو اور مثال کے طو رپر انسان اپنے دین وایمان کی حفاظت کی خاطر یا اس کی دعوت کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس صورت پر حرمت کا اطلاق نہیں ہوتا۔
آپ نے جس روایت کا حوالہ دیا ہے، اس میں بیان ہونے والے واقعے کی نوعیت یہی ہے۔ اس راہب پر یہ بات واضح تھی کہ ایمان لانے کے جرم میں کافر بادشاہ کے ہاتھوں اس کا مرنا یقینی ہے، البتہ اللہ کی حکمت کے تحت اس کی اب تک کی کوششیں ناکام رہی ہیں۔ اس وجہ سے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنی موت کا ایک ایسا طریقہ خود تجویز کر دے جس میں اسے لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچانے کا موقع بھی میسر آ جائے۔ قتل کی متعدد کوششوں سے اس کا بچ نکلنا لوگوں میں معروف ہو چکا تھا اور یقینا وہ ایسے شخص کے بارے میں جاننے کا تجسس بھی رکھتے تھے، اس لیے اس بات کی قوی امید تھی کہ اگر اسے اس کے تجویز کردہ طریقے کے مطابق ‘باسم رب هذه الغلام’ (اس لڑکے کے رب کے نام سے) کہہ کر قتل کیا گیا تو یہ چیز لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تک حق کا پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ چنانچہ یہی ہوا اور روایت کے مطابق اس کی شہادت کا منظر دیکھنے والے لوگوں کی اکثریت نے ایمان قبول کر لیا۔ اسی روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب بادشاہ کو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس نے ایک بڑی آگ بھڑکا کر ان سب لوگوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ یا تو وہ اپنے ایمان سے دست بردار ہو جائیں اور یا پھر ایک ایک کر کے اس آگ میں کود جائیں۔ اہل ایمان نے خود آگ میں کود کر جان دینا منظور کر لیا لیکن ایمان سے دست بردار نہ ہوئے، بلکہ ایک خاتون اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ لائی گئی اور اس نے بھڑکتی ہوئی آگ کو دیکھ کر کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو اللہ کی قدرت سے اس کے دودھ پیتے بچے نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ ‘يا امه اصبری فانك علی الحق’ (اے میری ماں، صبر سے کام لو کیونکہ تم حق پر ہو) اور بچے کی اس حوصلہ افزائی پر اس کی ماں بھی آگ میں کود گئی۔ (مسلم، رقم ٣٠٠٥)
جہاں تک جنگ میں شہادت کے حصول کی غرض سے دشمن پر خود کش حملہ کرنے کا تعلق ہے تو اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شہادت دراصل کفار کے ہاتھوں قتل ہونے کو کہتے ہیں، نہ کہ دشمن کو نقصان پہنچانے کی غرض سے ازخود اپنے آپ کو قتل کرنے کے اقدام کو۔ چنانچہ ایک غزوے میں جب ایک صحابی دشمن پر وار کرنے کی ناکام کوشش میں خود اپنی ہی تلوار سے زخمی ہو کر فوت ہو گئے تو صحابہ کو اس پر تردد ہوا کہ آیا یہ ان کی شہادت کی موت ہے یا خود کشی کی، تاہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ (مصنف عبد الرزاق، رقم١٧٨٢٨) یعنی چونکہ اس کی نیت خود کشی کی نہیں تھی اور ایسا خطا سے ہوا ہے، اس لیے اسے اللہ کے ہاں شہید ہی شمار کیا جائے گا۔ البتہ مخصوص حالات میں، خاص طور پر جب کہ میدان جنگ میں موت یقینی دکھائی دے رہی ہو، اپنی جان کی قربانی دے کر مسلمانوں کو کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے دشمن پر خود کش حملے کے جواز سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اگر دشمن کی پیش قدمی کو روکنے یا طاقت کے تناسب کو متوازن کرنے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہ ہو تو اس صورت حال میں بھی اس کا جواز اور مشروعیت تسلیم نہ کرنے کی بظاہر کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ تاہم ایسے کسی بھی اقدام کے جواز کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس میں شریعت کے کسی دوسرے اصول اور ضابطے کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو۔ یعنی اگر جنگ کسی مشروع اور جائز مقصد کے لیے لڑی جا رہی ہواور اس میں دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کے لیے خود کش حملہ زیادہ موثر ہو اور اس کا نشانہ مقاتلین (combatants) ہی کو بنایا جائے تو اصولی طور پر اس خود کشی کو اس وعید کے تحت نہیں لایا جا سکتا جو حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ البتہ اگر جنگ کا محرک ہی ناجائز ہو اور حملے کا نشانہ دشمن کے مقاتلین کے بجائے عام انسانوں کو بنایا جائے تو اس صورت میں خود کش حملہ بھی اسی طرح ناجائز ہوگا جیسے کسی بھی دوسرے ہتھیار کا استعمال ناجائز ہے۔
٢۔ یہ استدلال کہ چونکہ امریکہ یا برطانیہ کے شہری اپنی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں جس کی مدد سے حکومت جنگ لڑتی ہے، اس لیے ٹیکس دینے والے تمام شہری ‘مقاتلین’ (combatants) ہیں اور انھیں جنگی حملے کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، شرعی اصولوں کی رو سے کسی طرح درست نہیں۔ اسلامی شریعت کی رو سے عام لوگ جو جنگ میں براہ راست شریک نہیں، انھیں ‘مقاتل’ قرار نہیں دیا جا سکتا، چاہے وہ اپنی حکومت کو ٹیکس دیتے ہوں اور جنگ کے فیصلے کو ان کی اصولی تائید حاصل ہو۔ ‘مقاتل’ اس کو کہا جائے گا جو جنگ میں براہ راست شریک ہو یا بالفعل لڑنے والوں کی ایسی مدد کر رہا ہو جو ”لڑائی میں مدد” کے زمرے میں آتی ہو۔ اس سے ہٹ کر اصولی طو ر پر جنگ کے فیصلے کی تائید کرنے والوں یا مقاتلین کی مدد کی بعض دوسری صورتیں اختیار کرنے والوں کو ‘مقاتل’ نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین میدان جنگ میں دشمن کے لشکر کے ساتھ آئی ہوئی خواتین اور کام کاج کرنے والوں خادموں کو، جو ظاہر ہے کہ اپنے لشکر کی مدد ہی کے لیے ساتھ آئے تھے، قتل کرنے سے منع فرمایا۔
حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزوے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک عورت کو مقتول دیکھا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے فرمایا:
ما کانت هذه تقاتل فی من يقاتل، انطلق الی خالد فقل له ان رسول الله صلی الله عليه وسلم يامرك يقول لا تقتلن ذرية ولا عسيفا (ابن ماجه، رقم ٢٨٤٢)
”یہ لڑنے والوں کے ساتھ لڑائی میں تو شریک نہیں تھی۔ …. خالد کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمھیں حکم دیتے ہیں کہ بچوں اور خادموں کو ہرگز قتل نہ کرنا۔”
ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں:
وجدت امراة مقتولة فی بعض مغازی رسول الله صلی الله عليه وسلم فنهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان (بخاری، رقم ٣٠١٥)
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غزوے میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو آپ نے عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا۔”
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سردار ابن ابی الحقیق کو قتل کرنے کے لیے صحابہ کا دستہ بھیجا تو انھیں عورتوں اور بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اس دستے کے ایک مجاہد عبد اللہ بن انیس بتاتے ہیں کہ:
برحت بنا امراة ابن ابی الحقيق بالصياح فارفع السيف ثم ذکرت قول رسول الله صلی الله عليه وسلم فاکفه ولولا ذالك لاسترحنا منها (مسند ابی عوانه، ٦٥٨٧۔ مسند ابی يعلی، رقم ٩٠٧)
”ابن ابی الحقیق کی بیوی نے چیخ کر ہمارے خلاف مدد کے لیے بلانا چاہا تو میں نے تلوار بلند کر لی، لیکن پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد آ گیا اور میں نے اپنی تلوار روک لی۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو ہم اس کی بیوی کا قصہ بھی پاک کر دیتے۔”
یہاں دیکھ لیجیے، خاتون کے چیخ پکار کے ذریعے سے مجاہدین کو خطرے میں ڈالنے کے باوجود انھوں نے اسے قتل کرنے سے گریز کیا۔
ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ:
نهی رسول الله صلی الله عليه وسلم عن قتل العسفاء والوصفاء (سنن سعيد بن منصور، رقم ٢٦٢٨)
”نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں اور خادموں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔”
سیدنا عمر نے اپنے فوجی سالاروں کو ہدایت دی کہ:
اتقوا الله فی الفلاحين فلا تقتلوهم الا ان ينصبوا لکم الحرب (سنن البيهقی الکبریٰ، رقم ١٧٩٣٨)
”ان کسانوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو جو تمھارے مقابلے میں جنگ کے لیے نہیں آتے۔”
ظاہر ہے کہ دشمن کے جن کسانوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، وہ لازماً اپنی زمین کی پیداوار کا ٹیکس حکمرانوں کو دیتے ہوں گے اور جنگ کے عسکری اخراجات میں ان کا بالواسطہ حصہ پڑا ہوگا، لیکن اس کے باوجود سیدنا عمر نے انھیں ‘مقاتل’ شمار نہیں کیا، الا یہ کہ وہ بالفعل جنگ میں حصہ لیں۔
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ:
کانوا لا يقتلون تجار المشرکين (مصنف ابن ابی شيبه، رقم ٣٣١٣٠)
”صحابہ مشرکین کے تاجروں کو قتل نہیں کرتے تھے۔”
یہاں بھی دیکھ لیجیے، صحابہ نے دشمن کے ایسے تاجر اور مال دار حضرات کو قتل کرنے سے گریز کیا ہے جن کے سرمایے سے یقینا ان کی فوجیں بھی فائدہ اٹھاتی ہوں گی۔
عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے ‘وقاتلوا فی سبيل الله الذين يقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين’ (اور اللہ کے راستے میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا) کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انھوں نے لکھا کہ:
ان ذلك فی النساء والذرية ومن لم ينصب ذلك الحرب منهم (مصنف ابن ابی شيبه، رقم ٣٣١٢٦)
”یہ ممانعت عورتوں، بچوں اور ان لوگوں سے متعلق ہے جو اس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں نہ آئے ہوں۔”
اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہدایت دی کہ:
الا لا يجهزن علی جريح ولا يتبعن مدبر ولا يقتلن اسير (ابو عبيد، الاموال، ص ١٤٢)
”سنو، کسی زخمی کو قتل نہ کیا جائے، کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کیا جائے اور کسی قیدی کو قتل نہ کیا جائے۔”
مذکورہ ہدایات سے واضح ہوتا ہے کہ دشمن قوم کے جو افراد بعض پہلووں سے دشمنوں کے لشکر کی مدد کرنے کے باوجود خود جنگ میں شریک نہ ہوں یا جنگ میں شریک ہونے کے بعد زخمی یا گرفتار ہو جانے کی وجہ سے لڑنے کے قابل نہ رہے ہوں، شریعت اسے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ غیر مقاتلین کا حملے کی زد میں آجانا صرف اس صورت میں معاف ہے جب حملے کا ہدف اصلاً مقاتلین ہوں اور تمام تر احتیاطی تدابیر کے باوجود قصد اور نیت کے بغیر ناگزیر طور پر یا اتفاقاً کچھ غیر مقاتلین بھی زد میں آ جائیں۔
مذکورہ تشریح کی روشنی میں بعض لوگوں کے اس نقطہ نظر کی غلطی بالکل واضح ہو جاتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلسطین میں اسرائیل کے ظلم وستم کا شکار ہونے والا کوئی شخص امریکہ یا برطانیہ میں جا کر وہاں کے ٹیکس دینے والے عام لوگوں پر خود کش حملہ کر دے تو یہ جائز ہوگا۔
٣۔ انسانوں کے بنائے ہوئے کسی بھی قانون کی اطاعت کو ‘کفر’ صرف اس صورت میں قرار دیا جا سکتا ہے جب وہ اللہ کے دیے ہوئے کسی قانون سے ٹکراتا ہو اور اللہ کے قانون سے سرکشی کرتے ہوئے یا اسے عمداً نظر انداز کرتے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے کسی قانون کو اختیار کر لیا جائے۔ سورئہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے اسی طرز عمل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ:
ومن لم يحکم بما انزل الله فاولئك هم الکافرون (آيت ٤٤)
”اور جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہی لوگ کافر ہیں۔”
یعنی کافر ہونے کا فتویٰ اس صورت میں ہے جب کسی معاملے میں اللہ نے کوئی قانون اتارا ہوا ہو اور انسان اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے گریز کریں۔ اس سے واضح ہے کہ اس متعین اور محدود دائرے سے ہٹ کر جس میں اللہ نے شریعت کا کوئی ابدی قانون اتارا ہے، دوسرے کسی معاملے میں نہ تو انسان پر اپنے عقل وفہم اور تجربے کی روشنی میں قانون بنانے پر کوئی پابندی ہے اور نہ ایسے کسی قانون کی پیروی کو محض اس بنیاد پر کفر قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں۔ قرآن مجید نے ‘کفر’ کا یہ فتویٰ ان یہود کے بارے میں دیا ہے جن کے پاس تورات موجود تھی او روہ اس کے احکام پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح آزاد تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات اور مفادات کی پیروی میں اس سے گریز کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ نیز یہ بھی ملحوظ رہنا چاہیے کہ قرآن نے یہاں ‘کفر’ کا لفظ کفر عملی کے معنی میں استعمال کیا ہے نہ کہ کفر اعتقادی اور کفر قانونی کے معنی میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ طرز عمل اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایک کافرانہ طرز عمل ہے۔ جہاں تک دنیا کے ظاہری احکام کے لحاظ سے کسی کو کافر قرار دینے کا تعلق ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے اور جب تک کوئی شخص کسی تاویل کے بغیر کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت کو قبول نہ کرنے یا انھیں مسترد کرنے کا اعلان نہ کر دے، اسے کافر قرار دینے اور اس پر کفر کے ظاہری قانونی احکام جاری کرنے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔
مذکورہ توضیح پیش نظر رہے تو واضح ہوگا کہ اگر مسلمان اپنے آپ کو کسی ایسی صورت حال میں پائیں جہاں قانون سازی کا کلی اختیار ان کے پاس نہ ہو، جیساکہ غیر مسلم ممالک میں مقیم مسلمانوں کی صورت حال ہے، اور وہ عملی مجبوریوں کے تحت شرعی قوانین پر عمل نہ کر سکیں تو اس پر مذکورہ وعید کا اطلاق نہیں ہوتا، البتہ ایسی صورت میں مسلمان اس بات کے مکلف ہوں گے کہ وہ اپنے امکان کی حد تک شرعی قوانین پر عمل کی کوشش کریں اور اس بات کی بھی جدوجہد کرتے رہیں کہ ریاستی قانون میں مسلمانوں سے متعلق معاملات میں شرعی احکام کو قانونی تحفظ حاصل ہو جائے۔ یہ جدوجہد اس معاہدئہ سکونت یا معاہدئہ شہریت کی شرائط کے دائرے میں ہونی چاہیے جس کے تحت مسلمان ان ممالک میں رہ رہے ہیں، کیونکہ ملک کے عمومی قوانین کو توڑ کر یا انھیں چیلنج کرتے ہوئے ایسی کوئی جدوجہد شریعت کی نظر میں معاہدے کی خلاف ورزی قرار پائے گی۔ میرے فہم کے مطابق جائز دنیوی اور دینی مصلحتوں کے تحت مسلمانوں کا غیر مسلم ممالک میں سکونت پذیر ہونا ازروے شریعت جائز ہے اور ایسی صورت حال میں جن شرعی احکام پر عمل کرنا ان کے لیے ممکن نہ ہو، وہ ان کے مکلف نہیں ہیں۔ اسلامی شریعت کے کلی نفاذ کا میدان غیر مسلم ممالک نہیں، بلکہ مسلمان معاشرے ہیں، اس لیے اگر کچھ مسلمان غیر مسلم معاشروں کے قانون اور ماحول پر اطمینان محسوس نہ کریں تو انھیں چاہیے کہ وہ کسی مسلم معاشرے میں سکونت اختیار کر لیں، نہ یہ کہ غیر مسلم معاشروں کے نظم اور قانون کو چیلنج کرتے ہوئے دین کی دعوت اور اس پر عمل کے ان مواقع سے بھی مسلمانوں کو محروم کر دیں جو انھیں اس ماحول میں میسر ہیں۔ هذا ما عندی والله اعلم
مجیب: Ammar Khan Nasir
اشاعت اول: 2015-10-10